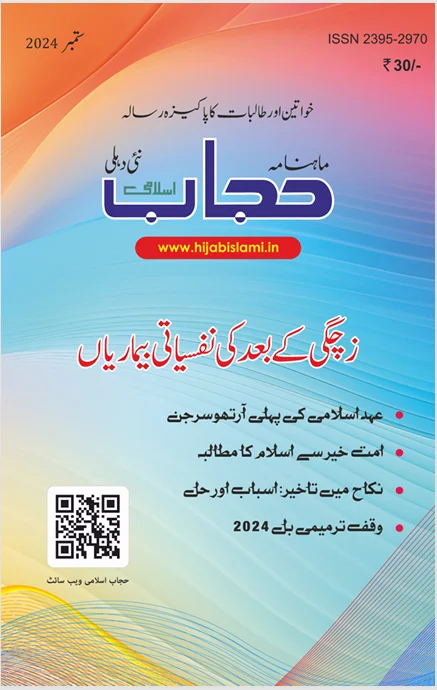اسلام نے عورتوں کو سماج میں مردوں کے مساوی حیثیت دی اور انھیں بھی وراثت کا مستحق قرار دیا۔د نیا یہ جانتی ہے کہ اسلام سے پہلے عورت کی کیا حالت تھی۔ وراثت تو ایسے میں دور کی بات ہے۔ قرآن کریم نے پوری صراحت اورقوت کے ساتھ اس کا اعلان کیا:
’’مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہو اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، خواہ تھوڑا ہویا بہت اور یہ حصہ (اللہ کی طرف سے) مقرر ہے۔ ‘‘ (النساء:۷)
اس آیت میں چند نکات قابل غورہیں:
۱- یہ نہیں کہا گیا کہ میراث میں مردوں اور عورتوں، سب کا حصہ ہے، بلکہ عورتوں کے حصہ کی الگ سے، مستقل طور پر صراحت کی گئی۔ اس سے عہد جاہلیت کے تصور کی کہ میراث میں عورتوں کا کوئی حصہ نہیں، پُرزور تردید اور عورتوں کے مستحقِ وراثت ہونے کی تاکید مقصود ہے۔
اس آیت میں یہ بھی واضح کردیا گیا کہ استحقاق میراث کے معاملے میں مردوں اور عورتوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ دونوں اس کے مستحق ہیں۔
۲-یہ صراحت کردی گئی کہ مالِ وراثت چاہے زیادہ ہو یا کم ، ہر حال میں عورتیں بھی اس میں سے حصہ پائیں گی۔ عموم کا تقاضا ہے کہ وراثت میں آنے والی وہ چیزیں بھی، جو صرف مردوں کے کام آتی ہیں، انھیں مردوں کے لیے خاص کرکے الگ کرلینا جائز نہیں، بلکہ وہ بھی تقسیم ہوں گی اور عورتیں ان میں سے بھی حصہ پائیں گی۔
۳- آخر میں نصیباً مفروضاً (مقرّر حصہ) کہہ کر مزید تاکید کردی گئی کہ مال وراثت میں عورتوں کا حصہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ ہے۔ اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کی جاسکتی، نہ انھیں بالکلیہ محروم کیا جاسکتا ہے۔
تقسیمِ میراث کا پیمانہ حصۂ نسواں
اسلام کی جانب سے عورتوں کی مزید عزّت افزائی کا مظہر یہ ہے کہ اس نے تقسیم میراث میں حصۂ نسواں کو اصل پیمانہ قرار دیا اور اس کی نسبت سے مردوں کا حصہ بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:
’’تمھاری اولاد کے بارے میں اللہ تمھیں ہدایت کرتا ہے کہ ایک مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے۔‘‘ (النساء:۱۱)
قرآن کی یہ تعبیر قابلِ غور ہے۔ یوں بھی کہا جاسکتا تھا کہ عورت کے لیے مرد کے حصہ کا نصف ہے یا دو عورتوں کو ایک مرد کے برابر حصہ ملے گا۔ لیکن اس کے بجائے یہ کہا گیا کہ مرد کے لیے دوعورتوں کے حصے کے برابر ہے۔اس کی حکمت یہ ہے کہ قرآن کی نظر میں میراث میں لڑکی کا حصہ اصل ہے، اسی لیے اسے تقسیم میراث کے معاملے میں پیمانہ اور بنیاد بنایا گیا ہے۔ اس حکمت کی طرف عہد حاضر کے مشہور مصلح اور مفسّر شیخ محمد عبدہٗؒ نے اشارہ کیا ہے۔ لکھا ہے:
’’اس جملہ میں یہ تعبیر یہ بتانے کے لیے اختیار کی گئی ہے کہ اہلِ جاہلیت نے عورتوں کو میراث سے محروم کرنے کا جو طریقہ اپنا رکھا تھا، اسے باطل قرار دے دیا گیا ہے۔ گویا میراث میں عورت کا حصہ مقرر کردیا گیا اور بتادیا گیا کہ مرد کو اس کا دوگنا ملے گا، یا عورت کے حصے کو قانونِ میراث میں اصل قرار دیا گیا اور مرد کے حصے کو اس پر محمول کیا گیا، جسے اس کی نسبت سے جانا جاسکتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو یوں کہا جاتا کہ عورت کے لیے مرد کے حصہ کا نصف ہے۔ اس صورت میں یہ مفہوم حاصل نہ ہوتا اور سیاق بھی اس سے مطابقت نہ رکھتا۔ ‘‘
اس بات کو مزید مدلّل کرتے ہوئے شیخ رشید رضاؒ نے لکھا ہے کہ میراث کی دونوں آیتوں (النساء: ۱۱-۱۲) میں تقسیم میراث کی جو صورتیں مذکور ہیں، ان میں عورتوں کا حصہ صراحت کے ساتھ پہلے بیان کیا گیا ہے۔
مستحقینِ وراثت میں عورتوں کا تناسب
اسلام میں مستحقینِ وراثت کی جو ترتیب قائم کی گئی ہے اس میں اہم ترین دوہیں:
(۱) اصحاب الفرائض (۲) عصبہ
اصحاب الفرائض سے مراد وہ لوگ جن کے حصے قرآن، حدیث یا اجماعِ امت سے متعین کردیے گئے ہیں۔ عصبہ ان وارثوں کو کہا جاتا ہے جو اصحاب الفرائض میں میراث کی تقسیم کے بعد بچے ہوئے حصے کے مستحق بنتے ہیں۔
رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:
’’میراث اصحابِ فرائض کے درمیان تقسیم کرو، پھر جو بچ جائے وہ میت کے سب سے قریبی مرد کے لیے ہے۔‘‘
(الف) اصحاب الفرائض
اصحاب فرائض بارہ ہیں:
(۱) باپ (۲) دادا (۳) اخیافی (ماں شریک ) بھائی (۴) شوہر (۵) ماں (۶) دادی (۷) بیٹی (۸) پوتی (۹) حقیقی بہن (۱۰) علاّتی (باپ شریک) بہن (۱۱)اخیافی (ماں شریک) بہن (۱۲) بیوی ۔
ان میں شوہر اور بیوی زوجیت کی بنا پر وارث قرار پاتے ہیں، اس لیے انھیں اصحاب الفرائض سببی کہتے ہیں۔ بقیہ لوگ قرابت و نسب کی بناپر وارث بنتے ہیں، اس لیے انھیں اصحاب الفرائض نسبی کہا گیا ہے۔
ان میں چار مرد اور آٹھ عورتیں ہیں۔ اسی سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ اسلام نے تقسیم میراث کے معاملے میں عورتوں کو کتنی اہمیت دی ہے اور کتنی فراخ دلی سے ان کا حصہ متعین کیا ہے۔
(ب) عصبہ
عصبہ کی متعدد ذیلی تقسیمیں ہیں:
(الف) عصبہ بنفسہ: وہ مستحق وراثت جس کا میت سے رشتے کے درمیان کسی عورت کا واسطہ نہ ہو۔ مثلاً: (۱) بیٹا یا پوتا وغیرہ (۲) باپ یا دادا وغیرہ (۳) بھائی یا بھتیجا وغیرہ (۴) چچا یا چچازاد بھائی وغیرہ۔ یہ سب مرد ہوتے ہیں۔
(ب) عصبہ بغیرہ : یہ وہ عورتیں ہیں جن کا میراث میں حصہ متعین ہے، لیکن اپنے بھائی کی موجودگی میں وہ اس کے ساتھ عصبہ بن جاتی ہیں اور ان کا متعین حصہ ختم ہوجاتا ہے۔ یہ چار ہیں:
(۱) بیٹی (۲) پوتی (۳) حقیقی بہن (۴) علاّتی (باپ شریک) بہن
(ج) عصبہ مع الغیر۔ یہ بھی عورتیں ہوتی ہیں جو بیٹی یا پوتی کی موجوگی میں عصبہ بن جاتی ہیں اور ان کے متعین حصوں کی تقسیم کے بعد بقیہ میراث کی مالک ہوتی ہیں، بہ شرطے کہ ان کا بھائی موجود نہ ہو۔ یہ دو ہیں:
(۱) حقیقی بہن
(۲) علاّتی (باپ شریک ) بہن
اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ عصبہ ہونے کے معاملے میں بھی اسلام نے عورتوں کو محروم نہیں کیاہے، بلکہ انھیں مستحقِ میراث قرار دیا ہے۔
کسی حال میں محروم نہ ہونے والے وارثوں میں عورتیں بھی ہیں
مستحقینِ میراث میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو دوسرے وارثین کی موجودگی میں میراث سے بالکلیہ محروم ہوجاتے ہیں، مثلاً بھائی جو باپ کی موجودگی میں محروم رہتا ہے اور بعض لوگ وہ ہیں جو بالکلیہ تو محروم نہیں ہوتے، البتہ ان کا حصہ کم ہوجاتا ہے۔
چھ وارث ایسے ہیں جو کسی بھی حال میں بالکلیہ میراث سے محروم نہیں ہوتے:
(۱) شوہر (۲) بیٹا (۳) باپ (۴) بیوی (۵) بیٹی (۶) ماں (ان میںسے بیٹا عصبہ میں سے ہے اور بقیہ اصحاب فرائض میں سے )۔
اس فہرست میں اگر تین مرد ہیں تو تین عورتیں بھی ہیں۔
میراث کے متعین کردہ حصے اوران میں عورتوں کا استحقاق
میراث میں اصحاب فرائض کے جو حصے متعین کیے گئے ہیں، ان کے مستحقین میں عورتوں کی تعداد مردوں کے مقابلے میں تین گنی ہے۔ اس کی تفصیل درج ذیل جدول میں پیش کی جارہی ہے:
اس جدول سے درج ذیل باتیں معلوم ہوتی ہیں:
۱- اصحاب فرائض کی حیثیت سے عورتیں سترہ(۱۷) حالتوں میں حصہ پاتی ہیں، جب کہ مرد صرف چھ حالتوں میں مستحق بنتے ہیں۔
۲- سب سے بڑا حصہ (دو تہائی) مردوں میں سے کسی کو نہیں ملتا، جب کہ چار طرح کی عورتیں اس کی مستحق ہوتی ہیں۔
۳- نصف حصہ مردوں میں سے صرف شوہر کو ملتا ہے اور وہ بھی صرف اس صورت میں جب متوفیہ کی کوئی اولاد نہ ہو (اور یہ صورت بہت کم پیش آتی ہے)، جب کہ یہ حصہ چار طرح کی عورتوں کو ملتا ہے۔
۴- تہائی حصے کی مستحق دو طرح کی عورتیں ہوتی ہیں اور ایک مرد۔
۵- چھٹے حصے کے مستحق آٹھ افراد ہوتے ہیں، جن میں سے مرد تین ہیں، جب کہ عورتوں کی تعداد پانچ ہے۔
۶- چوتھائی حصہ شوہر بھی پاتا ہے اور بیوی بھی۔ شوہر اس صورت میں جب متوفیہ کی کوئی اولاد ہو، اور بیوی اس صورت میں جب میت کی کوئی اولاد نہ ہو۔
۷- آٹھواں حصہ صرف بیوی کو ملتا ہے، جب کہ متوفی کی کوئی اولاد موجود ہو۔
وہ حالات جن میں عورت کا حصہ مرد کے برابر ہے
تقسیم میراث کے متعدد حالات ایسے ہیں جن میں عورت کا حصہ مرد کے برابر ہوتا ہے اور ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں ہوتی۔وہ حالات درج ذیل ہیں:
۱- میت کے وارثین میں اگر اس کی اولاد بھی ہو اور والدین بھی تو ماں باپ میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:
’’اگر میت صاحبِ اولاد ہو تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا چھٹا حصہ ملنا چاہیے۔‘‘ (النساء:۱۱)
۲- میت کے اصول (یعنی باپ، دادا وغیرہ) اور فروع (یعنی بیٹا ، پوتا وغیرہ) میں کوئی نہ ہو اور اس کا صرف ایک اخیافی (ماں شریک) بھائی یا بہن ہو تو دونوں صورتوں میں اسے چھٹا حصہ ملے گا اور اگر یہ بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں تو سب ایک تہائی میں برابر کے حصہ دار ہوں گے۔
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:
’’اور اگر وہ مرد یا عورت (جس کی میراث تقسیم طلب ہے) بے اولاد بھی ہو اور اس کے ماں باپ بھی زندہ نہ ہوں مگر اس کا ایک بھائی یا ایک بہن موجود ہو تو بھائی اور بہن ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا، اور بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں تو کل ترکہ کے ایک تہائی میں وہ سب شریک ہوںگے۔‘‘ (النساء:۱۲)
اس آیت میں ’کلٰلۃ‘ سے مراد وہ شخص ہے جس کے اصول و فروع میں سے کوئی نہ ہو اور ’اخ‘ (بھائی) اور ’اخت‘ (بہن) سے مراد اخیافی (ماں شریک) بھائی بہن ہیں۔ اس مفہوم پر امت کااجماع ہے۔
۳- بعض حالات میں حقیقی بہن اتنا ہی حصہ پاتی ہے جتنا حقیقی بھائی مستحق بنتا ہے، مثلاً:
(الف) متوفیہ کے وارثین میں صرف شوہر اور حقیقی بھائی ہو تو شوہر کو نصف میراث ملے گی اور حقیقی بھائی عصبہ ہونے کی بنا پر باقی میراث (نصف) پائے گا۔ اسی طرح اگر اس کے وارثین میں صرف شوہر اور حقیقی بہن ہوں تو دونوں کے درمیان میراث نصف نصف تقسیم ہوگی۔
(ب) اگر متوفیہ کے وارثین میں صرف شوہر، بیٹی اور حقیقی بھائی ہو تو شوہر کو چوتھائی اور بیٹی کو نصف میراث ملے گی اور حقیقی بھائی عصبہ ہونے کی بناپر باقی میراث (چوتھائی) پائے گا۔ اسی طرح اگر اس کے وارثین میں شوہر، بیٹی اور حقیقی بہن ہوں تو شوہر کو چوتھائی اور بیٹی کو نصف میراث ملے گی اور حقیقی بہن بیٹی کے ساتھ عصبہ ہونے کی بناپر باقی میراث (چوتھائی) کی مستحق ہوگی۔
عورت کاحصہ مرد کانصف ہونے کی بعض حالتیں
ان صورتوں کے ساتھ جن میں عورت کاحصہ مرد سے زیادہ ہوتا ہے یا اس کے برابر، چند مخصوص حالتیں ایسی بھی پائی جاتی ہیں جن میں عورت کاحصہ مرد کا نصف ہوتا ہے۔ وہ درج ذیل ہیں:
۱- اگر میت کے وارثین میں صرف اس کے ماں باپ ہوں (کوئی اولاد اور شوہر یا بیوی نہ ہو) تو ماں کا حصہ ایک تہائی ہوتاہے اور بقیہ (دو تہائی) کا مستحق باپ قرار پاتا ہے۔
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:
’’اگر وہ صاحب اولاد نہ ہو اور والدین ہی اس کے وارث ہوں تو ماں کے لیے تہائی حصہ ہے۔‘‘
(النساء: ۱۱)
اس آیت میں صرف ماں کے حصے (ایک تہائی) کی صراحت ہے۔ اس سے استنباطی طور پر معلوم ہوتا ہے کہ باپ کا حصہ دوتہائی ہوگا۔
۲- اگر زوجین میں سے کوئی ایک وفات پاجائے اور دوسرے کو چھوڑ جائے تو عورت یعنی بیوی کاحصہ مرد یعنی شوہر کے مقابلے میں نصف ہوتا ہے۔ اگر اولاد ہو تو شوہر کو چوتھائی اور بیوی کو آٹھواں حصہ ملے گا اور اگر اولاد نہ ہو تو شوہر نصف اور بیوی چوتھائی حصہ پائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:
’’اور تمھاری بیویوں نے جو کچھ چھوڑا ہو اس کا آدھا حصہ تمھیں ملے گا اگر وہ بے اولاد ہوں، ورنہ اولاد ہونے کی صورت میں ترکہ کا ایک چوتھائی حصہ تمھارا ہے، جب کہ وصیت جو انھوں نے کی ہو پوری کردی جائے اور قرض جو انھوں نے چھوڑا ہو ادا کردیا جائے اور وہ تمھارے ترکہ میں سے چوتھائی کی حق دار ہوں گی اگر تم بے اولاد ہو۔ ورنہ صاحب اولاد ہونے کی صورت میں ان کا حصہ آٹھواں ہوگا، بعد اس کے کہ جو وصیت تم نے کی ہو وہ پوری کردی جائے اور جو قرض تم نے چھوڑا ہو وہ اداکردیا جائے۔ ‘‘ (النساء: ۱۲)
۳- اگر میت کی اولاد (بیٹے بیٹیاں) ہوں تو ان کے درمیان میراث اس طرح تقسیم ہوگی کہ ہر ایک لڑکے کو دو لڑکیوں کے برابر حصہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے:
’’اللہ تمھاری اولاد کے بارے میں تمھیں ہدایت دیتا ہے: مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے۔‘‘(النساء: ۱۱)
۴- اسی طرح اگر میت کے بھائی بہن (حقیقی یا علاّتی یعنی باپ شریک) ہوں تو ان کے درمیان بھی میراث اس طرح تقسیم ہوگی کہ ہر مرد کو دو عورتوں کے برابر حصہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے:
’’اوراگر کئی بھائی بہنیں ہوں تو عورتوں کا اکہرا اور مردوں کا دوہرا حصہ ہوگا۔‘‘(النساء:۱۷۶)
عورت کا حصہ کم ہونے کا سبب نظامِ معاشرت میں اس کی مخصوص پوزیشن ہے
ان صورتوں میں عورت کاحصہ مرد کانصف ہونے سے بہ ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ اس کی حق تلفی کی گئی ہے اور اسے اس کے استحقاق سے کم دیا گیا ہے، حالاںکہ ایسا نہیں ہے۔اسلامی نظامِ وراثت پر غائرانہ نظر ڈالی جائے اوراس کے خصائص ذہن میں مستحضر رہیں تو بہ خوبی واضح ہوتا ہے کہ ان صورتوں میں بھی اسے اس کے استحقاق اور احتیاج سے بڑھ کر دیا گیا ہے اوراس کی ادنیٰ سی بھی حق تلفی نہیں کی گئی ہے۔
مذکورہ صورتوں میں عورت کا حصہ مرد کانصف ہونے کی بنیادی وجہ اسلامی نظام معاشرت میں اس کی مخصوص پوزیشن ہے۔ اسلامی نظام معاشرت میں کمانے، گھر کا خرچ چلانے اور ماتحت افراد کی مالی کفالت کرنے کی ذمہ داری مرد پر عائد کی گئی ہے، جب کہ عورت کو معاشی جدّو جہد سے مستثنیٰ رکھا گیا ہے۔ بچپن میں اس کی کفالت باپ کے ذمے ہے، جوانی میں شادی کے بعد شوہر کے ذمّے اور بڑھاپے میں اولاد کے ذمے۔ وہ جس قدر مال کی مالک بنتی ہے سب اس کے پاس محفوظ رہتا ہے، دوسروں پر خرچ کرنا اس کی ذمہ داری نہیں، لیکن مرد جو کچھ مال حاصل کرتا ہے اسے زیر کفالت افراد پر خرچ کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ اس بنا پر یہ بات قرینِ انصاف ہے کہ مرد کاحصہ عورت کا دوگنا رکھا گیا ہے۔ اگر دونوں کا حصہ برابر کردیا جاتا تو یہ مرد کے ساتھ ناانصافی ہوتی۔ مفسرین کرام نے اس پہلو پر روشنی ڈالی ہے۔ علامہ ابن کثیرؒ فرماتے ہیں:
’’اللہ تعالیٰ نے ایک مرد کاحصہ دوعورتوں کے برابر رکھا ہے۔ اس لیے کہ مرد کو نفقہ کا بوجھ اور تکلیف، تجارت اور کسب معاش کی دشواری برداشت کرنی پڑتی ہے اور دوسری مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ اس لیے مناسب یہی ہے کہ اسے عورت کے حصے کا دوگنا دیا جائے۔‘‘
علامہ رشید رضاؒ نے لکھا ہے:
’’ایک مرد کا حصہ دوعورتوں کے حصے کے برابر کرنے کی حکمت یہ ہے کہ مرد کو اپنے اوپر بھی اور اپنی بیوی پر بھی خرچ کرنا پڑتا ہے، اس لیے اس کے دو حصے ہوئے، جب کہ عورت صرف اپنی ذات پر خرچ کرتی ہے اور اگر اس کی شادی ہوگئی ہو تو اس کا اپنانفقہ بھی اس کے شوہر پر واجب ہوتا ہے۔‘‘
مولانا امین احسن اصلاحیؒ نے لکھا ہے:
’’وراثت میں لڑکوں کا حصہ اللہ تعالیٰ نے لڑکیوں کے بالمقابل دونا رکھا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کے نظامِ معاشرت میں کفالتی ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے تمام تر مرد ہی پر ڈالی ہیں۔ عورت پر کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی ہے۔ مرد ہی بیوی کے نان نفقہ کا بھی ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے اور وہی بچوں کا بھی کفیل بنایا گیا ہے ۔۔۔ یہ چیز مقتضی ہوئی کہ مرد کو اس کی ذمہ داریوں کے لحاظ سے بعض حقوق میں ترجیح ہو‘‘۔
یہی وجہ ہے کہ جن صورتوں میں مرد کی معاشی ذمہ داریاں کم یا ختم ہوجاتی ہیں ان میں تقسیم میراث کے معاملے میں عورت اور مرد کے درمیان فرق نہیں کیا گیا ہے۔ مثلاً میت کی اولاد ہو اور اس کے ماں باپ بھی ہوں تو میراث میں ماں اور باپ ہر ایک کا چھٹا حصہ مقرر کیاگیا ہے۔ اس لیے کہ جس شخص کی اولاد بھی صاحبِ اولاد ہو اس کی معاشی ذمہ داری بڑی حد تک کم یا بالکل ختم ہوجاتی ہیں، اس کی حیثیت بالعموم اپنے پوتوں پوتیوں کے سرپرست کی ہوتی ہے، لیکن اگر میّت کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کا باپ صاحبِ اولاد ہو (یعنی میّت کے بھائی بہن ہوں) تو اس صورت میں اس (یعنی میّت کے باپ) کی معاشی ذمہ داری ہوسکتی ہے۔ اسی وجہ سے باپ کا حصہ ماں سے زیادہ رکھا گیا ہے (ماں کوایک تہائی اور باپ کو دو تہائی ملتا ہے)۔
مرد اور عورت کے حصوں میں تفاوت کی بنیاد جنس پر نہیں ہے
اسلامی شریعت میں تقسیم میراث کی بعض صورتوں میں مرد اور عورت کے حصوں میں جو فرق و تفاوت پایا جاتا ہے وہ جنس کی بنیاد پر نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو بیٹے کے مقابلے میں باپ کا اور بیٹی کے مقابلے میں ماں کا حصہ کم نہ ہوتا۔ مستحقینِ میراث کے حصوں میں فرق و امتیاز کن اصولوں کی بنیاد پر کیا گیا ہے، اس کی وضاحت کرتے ہوئے عصر حاضر میں عالم عرب کے مشہور دانش ور ڈاکٹر محمد عمارہ نے لکھا ہے:
’’میراث میں فرق و امتیاز کی بنیاد مرد و عورت ہونے پر نہیں ہے، بلکہ اس فرق کی بنیاد تین معیاروں اور اصولوںپرہے:
اول: وارث (خواہ مرد ہو یا عورت) اور میّت مورث کے درمیان درجۂ قرابت ہے۔ لہٰذا یہ قرابت جتنی قریب ہوگی اسی لحاظ سے میراث میں وارث کاحصہ زیادہ ہوگا۔
دوم: نسلوں کے زمانی تسلسل کے تناظر میں وارث ہونے والوں کی نوعیت اور حیثیت ہے، لہٰذا وہ نئی نسلیں جو زندگی کا استقبال کررہی ہیں، عام طور پر میراث میں ان کا حصہ ان پرانی نسلوں سے زیادہ ہوگا جو زندگی کو الوداع کہنے والی ہیں۔ اس میں وارثین کے مرد یا عورت ہونے کو معیار نہیں بنایا گیا ہے، مثلاً بیٹی ماں سے زیادہ حصہ پاتی ہے، حالاںکہ وہ دونوں ہی عورتیں ہیں، بلکہ بیٹی باپ سے بھی زیادہ حصہ پاتی ہے۔ اور بیٹا باپ سے زیادہ حصہ پاتا ہے، جب کہ وہ دونوں مرد ہیں۔
سوم: وہ مالی ذمہ داری ہے جسے شریعت دوسروں کی کفالت سے متعلق وارث پر لازم کرتی ہے۔ یہی وہ معیار ہے جو مردوزن کے درمیان تفاوت کا سبب بنتا ہے۔ شریعت میں ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر ہے۔ اس لیے کہ یہاں پر (درجۂ قرابت و نسل کی برابری کی حالت میں) مرد وارث اپنی بیوی کی کفالت کا مکلّف ہے، جب کہ وارث ہونے والی عورت کی کفالت اس مرد پر فرض ہے جو اس کا رفیقِ حیات ہے۔ اگر فرق کی ان صورتوں کاموازنہ میراث کی عام حالتوں سے کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ صورتیں بہت کم ہوتی ہیں‘‘۔
——