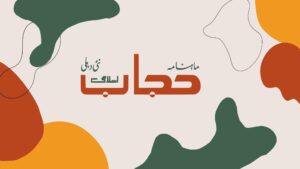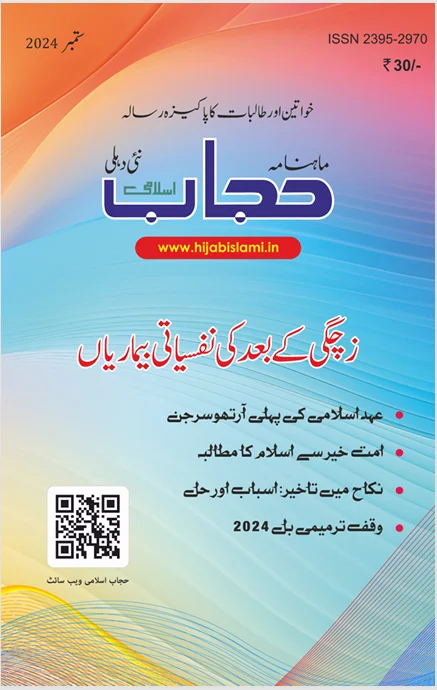اللہ کے رسولؐ کا ارشاد ہے۔ ’’میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ کارنبوت یہ ہے کہ وہ لوگوں کو حقیقی علم سے روشناس کرائے اور حقیقی علم وہی ہے جو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعہ اپنے رسول کو سکھاتاہے۔ اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ تعلیم و تدریس کا کام نبوی کام ہے۔ اور اس کارنبوت کو انجام دینے والے معلمین کو چاہیے کہ وہ یہ جانیںکہ انہیں اپنے بچوں کو کیا سکھانا ہے اور کیسے سکھانا ہے۔ ظاہر ہے جب اللہ کے رسول معلم بنا کر بھیجئے گئے تھے تو انہوںنے تعلیم کا کوئی نظریہ بھی پیش کیا ہوگا اور تعلیم و تدریس کو بنیاد بھی فراہم کی ہوگی۔
دین کے مطالعہ اور سیرت رسول کو جاننے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام کا تصور تعلیم تین ستونوں پر کھڑا ہے۔
۱۔ تعلیم کا مقصد انسان کو اللہ کی ذات سے روشناس کرانا ہے۔
۲۔ تعلیم کا مقصدانسان کو اچھا انسان اور بااخلاق بنانا ہے۔
۳۔ تعلیم کا مقصد فرد کی خوابیدہ صلاحیتوں کو بے دار کرکے انہیں پروان چڑھانا اور ترقی دینا ہے۔
ایک مسلمان کی زندگی کی ساری معنویت، قدروقیمت اور حسن و جمال اس بات میں ہے کہ وہ اپنے خالق، اپنے مالک اور اپنے رازق کو کتنا جانتا ہے؟ کتنا مانتا ہے؟ او راس سے کتنی محبت کرتاہے؟ فرض کیجیے ایک شخص کو مادی زندگی اور اس کائنات کے مادی پہلو کے بارے میں ایک کروڑ باتیں معلوم ہیں، اور ایک شخص خدا کی ذات یاصفات کے بارے میں صرف ایک بات جانتا ہے۔ ہمارے علم کی روایت کہتی ہے کہ جو شخص خدا کی ذات یا صفات کے بارے میں صرف ایک بات جانتا ہے وہ مادی زندگی کی ایک کروڑ باتیں جاننے والے شخص سے زیادہ ’’عالم‘‘ ہے، اس لیے کہ خدا کی ذات یا صفات کا علم خالق کا علم ہے، اور مادی چیزوں کا علم مخلوق کا علم ہے۔ خدا کی ذات یا صفات کا علم دائمی حقیقت کا علم ہے ، جب کہ مادی زندگی کا علم عارضی حقیقت کا علم ہے۔ خدا کی ذات یا صفات کا علم ہماری آخرت کے نتائج پر گہرا اثر ڈال سکتاہے ، اس کے برعکس مادی حقائق کا علم آخرت سے متعلق ہی نہیں ہے۔
انسان کو عارف باللہ بنانے کا ایک اسلوب یہ ہے کہ ہمارے علم اور ہماری تعلیم سے خدا ’’معلوم‘ بھی ہو، ’’محسوس‘‘ بھی ہو اور ’’نظر‘‘ بھی آئے۔ مثال کے طور پر ہم خدا کو قادر مطلق کہتے ہیں لیکن ہمارے علم اور ہماری تعلیم سے خدا کہیں قادر مطلق نہ معلوم ہوتا ہے نہ محسوس ہوتا ہے، نہ قادر مطلق نظر آتا ہے ۔ مثلاً ہم خدا کو رحمان کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا علم ایسا ہو کہ خدا کی رحمانیت سب کو معلوم بھی ہوجائے ، محسوس بھی ہوجائے اور نظر بھی آجائے۔ یہی خدا کی دیگر صفات کا معاملہ ہے۔ ہمارے مذہبی ادب کی ناکامی یہ ہے کہ وہ خدا کو ایک ذہنی تصور یا Mental constructبنا دیتا ہے۔ حالاں کہ خدا حی ہے اور قیوم ہے، لیکن اس کی دائمی حیات کی معنویت اور اس کے حسن و جمال کی ایک جھلک بھی ہمارے مذہبی ادب میں نہیں آپاتی۔ چنانچہ ہمار امذہبی ادب ذہن کو تو تھوڑا بہت متاثر کرتاہے مگر وہ نہ ہماری روح کو وجد میں لاتا ہے ، نہ دل کو روشن کرتاہے، نہ نفس کے تزکیہ میں ہماری کوئی مدد کرتا ہے۔ ہمارا خدا ایسا خدا ہے جس کے بارے میں قرآن مجید کہتاہے کہ وہ ہر آن نئی شان میں ہے۔ لیکن ہمارا علم اور ہماری تعلیم خدا کی کوئی شان ہم تک منتقل نہیں کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری تعلیم ہمیں عارف باللہ بنانے کے سلسلے میں کچھ بھی نہیں کرتی۔
ہماری علمی روایت کہتی ہے کہ علم اور تعلیم کا ایک بڑا مقصد انسان کو اچھا انسان اور با اخلاق مسلمان بنانا ہے۔ لیکن ہماری عام تعلیم کیا موجودہ مذہبی تعلیم تک کا یہ حال ہے کہ وہ انسان سازی کے عمل سے کوسوں دور کھڑی ہے۔ ہماری مذہبی تعلیم مذہب کو یا تو ایک ’’مجرد نظریہ‘‘ بنا دیتی ہے یا ’’قانونی حقیقت‘‘‘۔ یہ تعلیم مذہب کو کبھی ’’تجربہ‘‘ نہیں بناتی، مذہب کو کبھی ’’قال‘‘ سے ’’حال‘‘ نہیں بناتی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتاہے کہ ہم خدا سے تھوڑا بہت ڈر تو جاتے ہیں مگر اس سے کبھی محبت نہیں کرپاتے۔ اس صورت حال کی ایک وجہ یہ ہے کہ مذہب کی روایت معجزے کی روایت ہے اور ہماری تعلیم میں معجزے کا بیان نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس خلا کو پُر کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ قصص الانبیاء کو تعلیم کا جزوِ لاینفک بنا دیا جائے۔ اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سیرتِ طیبہ کے اُن پہلوئوں کو تعلیم کا ناگزیر حصہ بنا دیا جائے جو انسانی تعلقات اور معاملات سے متعلق ہیں۔ سیرت طیبہ کے یہ پہلو مذہب اور اس کی حقیقت کو جس طرح ہمارا تجربہ بناتے ہیں، اس کی کوئی مثال پیش نہیں کی جاسکتی۔ ہماری تعلیم میں صحابہ کرام، اولیاء اللہ اور علما کی زندگیوں سے استفادے کی بھی کوئی صورت موجودنہیں۔ چنانچہ ہمارا مذہبی علم مذہب کے حقیقی ذائقے سے محروم ہے۔
ہماری مذہبی روایت میں انسان کی جتنی تعریف ہوئی ہے اتنی شاید ہی کسی روایت میں ہوئی ہو۔ ہماری روایت میں انسان اشرف المخلوقات ہے، زمین پر اللہ تعالیٰ کانائب ہے، کائنات کا خلاصہ ہے۔ چنانچہ ہمار ا مذہب چاہتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچانے… اپنی روحانی، اخلاقی اور تخلیقی صلاحیتوں کا سراغ لگائے اور انہیں درجۂ کمال تک پہنچا کر اپنے شرف کا ثبوت بھی دے اور زندگی کی معنویت اور حسن و جمال میں بھی اضافہ کرے۔
مسلمانوں نے اپنی تاریخ کے ایک بڑے حصے میں ان تمام تصورات کو حقیقت بنایا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے بعد بھی مسلمانوں نے اتنا بڑا مذہبی علم پیدا کیا کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ روایت ہے کہ امام غزالی کے ایک معاصر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑے تھے۔ وہاں امام غزالی بھی موجود تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزالی کی طرف اشارہ کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھ رہے تھے کہ کیا آپ کی امتوں میں غزالی جیسا کوئی عالم موجود ہے؟ اور دونوں جلیل القدر انبیاء کا کہنا تھا کہ ان کی امتوں میں غزالی جیسا عالم موجود نہیں۔ مسلمانوں نے شاعری کی اتنی بڑی روایت پیدا کی ہے کہ صرف مولانا روم کی شاعری باقی قوموں کی تمام شاعری سے برتر ہے۔ ایجاد و اختراع کے میدان میں بھی مسلمانو ںنے دنیا کی امامت کی ہے۔ مسلمانوں نے فنِ تعمیر میں کمالات دکھائے ہیں۔ مسلمانوں نے داستان کی سب سے بڑی روایت تخلیق کی ہے۔ لیکن مسلمان اپنی تخلیقی روایت سے بھی دور ہوگئے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان کا تصور انسان پست ہوچکا ہے ، اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ انہوںنے خود کو دنیا کا امام سمجھنا چھوڑ دیاہے، اس کی تیسری وجہ وہ تصور تعلیم ہے جو یورپی طاقتوں کی ا ٓمد کے بعد مسلمانوں بالخصوص برصغیر کے مسلمانوں میں عام ہوا۔
موجودہ تعلیم نے روزگار کو تعلیم کا کعبہ بنا دیاہے۔ وہ دن ہے اور آج کا دن… ہماری تعلیم روزگار کا طواف کیے چلی جا رہی ہے۔ تعلیم کے اس نمونے نے ہمیں اسلام کے تصور تعلیم کی تینوں بنیادوں سے کاٹ دیا۔ یہاں تک ہم تصور کی سطح پر بھی ان سے آگاہ نہ رہے۔ تجزیہ کیا جائے تو سرسید کا تعلیمی نمونہ ایک تاریخی حادثے کے سوا کچھ نہ تھا۔ لیکن یہ حادثہ ہماری پوری تاریخ پر چھا گیا، اور نہ صرف یہ ، بلکہ ایک معیار بن گیا۔ حالاںکہ اس حادثے کی حقیقت صرف اتنی تھی کہ 1857ء کی جنگ آزادی کے بعد انگریز، مسلمانوں کے خلاف او رہندوئوں کے قریب ہوگئے او رانہوںنے ملازمتوں کے دائرے میں ہندوئوں کو بڑے پیمانے پر نوازنے کا سلسلہ شروع کردیا۔ اس صورت حال میں مسلمانوں کی معاشی حالت خراب ہونے لگی۔ چناں چہ سرسید نے مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ وہ بہتر ملازمتوں کے حصول کے لیے جدید تعلیم حاصل کریں۔ انہوںنے علی گڑھ میں خود ایک بڑے تعلیمی ادارے کی بنیاد رکھی۔ سرسید کا خیال تھا کہ اس تعلیمی ادارے سے علم اور ذہانت کا دریا نکلے گا اور مسلمان اس کے نتیجے میں ملازمتوں کی بار ش میں نہائیںگے۔ لیکن سرسید کی پہلی خواہش کبھی پوری نہ ہوئی۔ البتہ ان کی فراہم کردہ تعلیم سے بہت سے مسلمانوں کو بہتر روزگار ضرور فراہم ہوا۔ تاہم سرسید کے تعلیمی ماڈل کے حوالے سے بنیادی بات یہ ہے کہ اس ماڈل کی ضرورت اگر تھی بھی تو صرف عہدِ غلامی کے لیے تھے، اور آزادی کے ساتھ ہی اس نمونۂ تعلیم سے جان چھڑانے کی ضرورت تھی۔ لیکن آزادی کے بعد بھی تعلیم کے اس ماڈل کا تسلسل نہ صرف یہ کہ برقرار رہا بلکہ اس ماڈل کے سوا کسی ماڈل کا تصور بھی ممکن نہ رہا یہاں تک کہ اساتذہ ہوں یا عزیز و اقارب۔۔۔۔ دوست ہوں یا والدین۔۔۔۔۔ بچوں سے صرف ایک ہی بات کہی جاتی ہے: تمہیں پڑھنا ہے اور دل لگاکر پڑھنا ہے تاکہ اچھی سے اچھی ملازمت حاصل کرسکو، تاکہ تمہارے پاس اچھا سا گھر، کار اور زندگی کی دیگر آسائشیں ہوں۔ یہ تعلیم کے تصور کی توہین کی انتہا ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ روزگار زندگی کا بنیادی مسئلہ ہے اور وہ غلط نہیں کہتے۔ چنانچہ تعلیم کے موجودہ ماڈل کے بارے میں یہی کہا جاسکتا ہے کہ اسے تعلیم کا چوتھا یعنی آخری مقصد قرار دینے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ یعنی ماضی اور حال کو مربوط رکھ کر ایک تناظر میں دیکھا جائے تو ہمارے تعلیمی نمونے کے چار مقاصد ہوں گے:
(۱) انسان کو عارف باللہ بنانا
(۲) انسان کو بہتر انسان بنانا
(۳) انسان کی تخلیقی صلاحیتوں کو بیدار کرنا اور پروان چڑھانا
(۴) انسان کو بہتر روزگار کے حصول کے قابل بنانا
یہاں بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوسکتی ہے کہ تعلیم کا روایتی نمونہ معاش کے تصور سے بیگانہ تھا۔ ایسا نہیں تھا، بلکہ اس نمونے کا بنیادی خیال یہ تھا کہ اصل چیز علم ہے۔ علم ہی زراعت کو فروغ دیتا ہے، علم ہی ہماری تجارت کو پھیلاتا ہے اور علم ہی سرمایہ تخلیق کرتا ہے۔ چنانچہ جس کے پاس علم کا کمال ہوگا اس کے لیے معاش کبھی بھی مسئلہ نہیں بنے گا۔ تجزیہ کیا جائے تو علم سے معاش کو برآمد ہوتے دیکھنے اور علم کو معاش کے لیے حاصل کرنے کی نفسیات میں زمین آسمان کا فرق ہے۔
اسلام کا تصورِ تعلیم استاد کے تصور کے بغیر مکمل نہیں ہوسکتا۔ اسلام کے نزدیک کامل استاد دو چیزوں کے امتزاج سے وجود میں آتا ہے:
(۱) تقویٰ، (۲) علم
یہاں تقویٰ کا غالب مفہوم یہ ہے کہ استاد کے قول و علم میں تضاد نہ ہو، استاد جو کہتا ہو وہی کرتا بھی ہو۔ یہ صلاحیت طالب علم میں استاد کے حوالے سے تین چیزیں پیدا کرتی ہیں۔ تقویٰ انسانوں کے قلوب پر اثر انداز ہوتا ہے اور انہیں حق کے لیے تیار کرتا ہے، انہیں حق کے لیے Receptive بناتا ہے۔ تقویٰ دوسرا کام یہ کرتا ہے کہ طالب علم کے دل میں استاد کا وہ احترام پیدا کرتا ہے جو استاد کے کام کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ تقویٰ تیسرا کام یہ کرتا ہے کہ طالب علم کی توجہ استاد پر مرکوز کرادیتا ہے۔ علم ذہنوں کو تسخیر کرتا ہے۔ استاد کا علم جتنا زیادہ ہوگا، طالب علم کا ذہن استاد سے اتنا ہی متاثر ہوگا۔ تقویٰ ایک اخلاقی کمال ہے اور علم ایک ذہنی کمال ہے اور کمال کی مزاحمت ممکن نہیں، یا زیادہ دیر تک ممکن نہیں۔ طالب علم کو جیسے ہی یہ معلوم ہوتا ہے کہ استاد کا علم اس سے اتنا زیادہ ہے کہ ان کے درمیان موازنہ ممکن نہیں تو وہ استاد کے آگے ہتھیار ڈال دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ فی زمانہ طالب علم اساتذہ کی عزت نہیں کرتے۔ لیکن ہم نے جس استاد میں تقویٰ اور علم کا امتزاج دیکھا ہے اُس کے سامنے بدترین سے بدترین طالب علم کو سر جھکانے پر مجبور پایا ہے۔
اسلام کے تصورِ تعلیم میں استاد کی اہمیت کا ایک پہلو یہ ہے کہ اچھا استاد برے نصاب کو بھی اچھی طرح پڑھا سکتا ہے، ورنہ برا استاد اچھے نصاب کو بھی تباہ کردیتا ہے۔ اچھے استاد کی ایک خوبی یہ ہے کہ وہ اوسط درجے سے کم صلاحیت رکھنے والے طلبہ کو اوسط درجے کا طالب علم بنا دیتا ہے، اوسط درجے کے طلبہ کو ذہین طلبہ میں تبدیل کردیتا ہے اور ذہین طلبہ کو عبقری یا Genius بننے کی طرف مائل کرتا ہے۔ لیکن فی زمانہ ہمارے معاشرے میں تدریس کے شعبے کی زبوں حالی کا یہ عالم ہے کہ جس شخص کو کہیں نوکری نہیں ملتی وہ استاد بن جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عبقری یا Genius بننے کی صلاحیت رکھنے والے طالب علم ذہانت سے آگے نہیں بڑھ پاتے۔ ذہین طالب علم اوسط درجے کے طالب علم بن کر رہ جاتے ہیں، اور اوسط درجے کے طالب علم کند ذہن بن جاتے ہیں۔
——