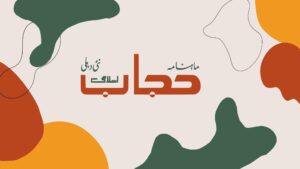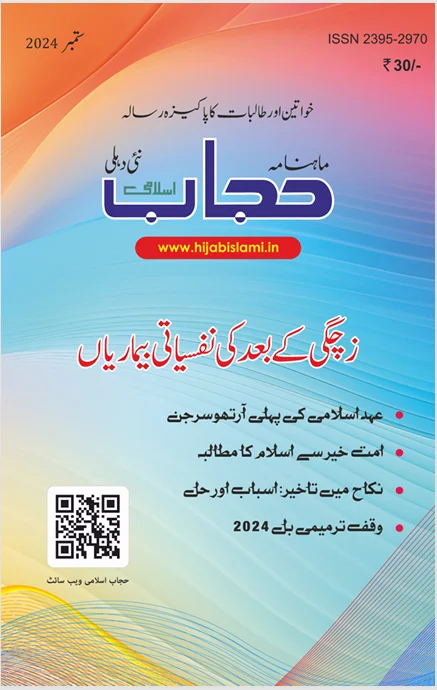انسانی تاریخ کا مطالعہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم ﷺ سے پہلے جن انبیا اور مرسلین کو بھیجا ان سب کی شریعتیں زمانی اور مکانی تھیں۔ یعنی وہ ایک خاص دور اور ایک خاص مقام کے لیے تھیں۔ چنانچہ ایک وقت کے بعد ان کی تعلیمات کا مسخ ہوجانا قرینِ قیاس تھا۔ چنانچہ عام طور پر اُس زمانے میں ایک نبی کو عطا ہونے والے عہد کی خرابیوں کو دوسرے نبی کی شریعت کے ذریعے دور کیا گیا۔ تاہم رسول اکرم ﷺ پر آکر نبوت کاسلسلہ ختم ہوگیا۔ لیکن امتِ مسلمہ میں بھی انسانوں کا یہ نقص موجود ہے کہ وہ نسیان میں مبتلا ہوتی ہے اور عقائد کو ان کی خالص ترین حالت میں برقرار نہیں رکھ پاتی۔ اس صورتِ حال کی اصلاح ناگزیر تھی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ میں مجددین کا سلسلہ قائم کیا جو ہر زمانے میں امت کی اصلاح کے لیے آتے رہے اور آتے رہیں گے۔ انسان کے نسیان اور حق کو خالص حالت میں برقرار نہ رکھ پانے کے مسئلے کو دیکھا جائے تو اس سے اصلاحِ معاشرہ کی ضرورت اور اہمیت پوری طرح واضح ہوکر سامنے آتی ہے۔
انسان کی زندگی کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس کا قول پوری طرح اس کا عمل نہیں بن پاتا جس سے قول یا حق کی قوت زائل ہوتی ہے اور معاشرے میں خرابی کی مختلف صورتیں سامنے آتی ہیں۔ خرابی کی یہ صورتیں بھی اصلاحِ معاشرہ کی اہمیت عیاں کرتی ہیں۔
اصلاحِ معاشرہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ جب تک برائی انفرادی معاملہ رہتی ہے اس کی خرابی، اس کا ضرر اور اس کا شر محدود رہتا ہے۔ لیکن برائی جب معاشرے میں عام ہوجاتی ہے تو اس کی خرابی، ضرر اور شر بہت بڑھ جاتا ہے۔ یہاں تک کہ خرابی ایک ’’نظام‘‘ بن جاتی ہے۔ خرابی کے نظام بنتے ہی اس میں ایک عظمت اور ایک شوکت پیدا ہوجاتی ہے۔ برائی کے نظام بن جانے کا ایک مطلب یہ ہے کہ برائی’’مدلل‘‘ بن گئی ہے۔ یہ تمام چیزیں مل کر برائی کی عمر کو بڑھا دیتی ہیں اور اس کی مزاحمت بہت مشکل ہوجاتی ہے۔
اس کی نسبتاً معمولی مثال بدعنوانی ہے جو کم و بیش ہر معاشرے میں ایک نظام پیدا کرلیتی ہے۔ اس حوالے سے اگلے مرحلے میں طرح طرح کے ’’مافیاز‘‘ وجود میں آتے ہیں جن کے خلاف جدوجہد انتہائی دشوار ہوجاتی ہے اور نظام کی طاقت معاشرے کو مسخ کردیتی ہے اور اس کی وحدت پارہ پارہ ہوجاتی ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ اس سے قبل ہی معاشرے کی اصلاح کرلی جائے تاکہ برائی کو یا تو بیج کی سطح پر ہی ختم کردیا جائے یا اس کا قلع قمع اس وقت کردیا جائے جب وہ ابھی صرف ایک پودا ہوتی ہے۔ برائی درخت بن جائے اور درخت باغ پیدا کرلیں تو پھر معاشرے کی اصلاح محال بلکہ بسا اوقات ناممکن ہوجاتی ہے۔
حضور اکرم ﷺ کی ایک حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ برائی کو قوت سے روک دو، یہ ممکن نہ ہو تو اس کے خلاف زبان سے جہاد کرو، یہ بھی ممکن نہ ہو تو اسے دل میں برا سمجھو، مگر یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ لیکن اب ہم جس دنیا کا حصہ ہیں اس میں صورتِ حال ان تینوں درجوںسے نیچے چلی گئی ہے۔ اب مسلم معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں جو برائی کو برائی ہی نہیں سمجھتے۔ اس سے بھی نچلا درجہ اُن لوگوں کا ہے جو برائی کے لیے جواز جوئی کرتے ہیں، جو برائی کو کسی نہ کسی بنیاد پر justifyکرتے ہیں۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ مسلم معاشروں میں لاکھوں لوگ سود کو برا نہیں سمجھتے، بلکہ مغربی نظریات سے متاثرہ لوگوں کی اچھی خاصی تعداد ایسی ہے جو سودی نظام کے حق میں دلائل دیتی ہے اور سمجھتی ہے کہ سود کے بغیر کاروبارِ حیات چلانا ممکن نہیں۔ ان حالات میں اصلاحِ معاشرہ کا کام آکسیجن کی طرح اہم ہوجاتا ہے، اس لیے کہ اصلاحِ معاشرہ کے ذریعے معاشرے میں حق و باطل کا فہم پیدا ہوتا ہے، ان کی تمیز پیدا ہوتی ہے، اور باطل کے خلاف جدوجہد کی راہ ہموار ہوجاتی ہے۔ یہاں سوال یہ ہے کہ اصلاحِ معاشرہ کا بنیادی اخلاقی تقاضا کیا ہے؟
قرآنِ مجید فرقانِ حمید سے جو اصول اس سلسلے میں ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ تم جو کچھ کہتے ہو وہ کرتے کیوں نہیں؟ یعنی اصلاحِ معاشرہ کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ جو شخص اصلاحِ معاشرہ کے لیے کھڑا ہو پہلے وہ خود اپنی اصلاح کرے، اپنے قول و فعل کے تضاد کو رفع کرے تاکہ وہ اخلاقی اہلیت اسے حاصل ہوسکے جو معاشرے کی اصلاح کے لیے ناگزیر ہے۔ یہ تقاضا پورا کیے بغیر کوئی شخص معاشرے کی اصلاح کا ’’علم بردار‘‘ تو ہوسکتا ہے مگر اس کا ’’مجاز‘‘ نہیں ہوسکتا۔ اس سلسلے میں حضور اکرم ﷺ کی سیرتِ طیبہ میں حد درجہ احتیاط پائی جاتی ہے۔
ہمارے دور میں اصلاحِ معاشرہ کی اکثر کوششوں کے غیرمؤثرہونے کا ایک سبب یہ ہے کہ اصلاح کرنے والے خود اصلاح یافتہ نہیں ہیں۔ اسلامی تاریخ کو دیکھا جائے تو اصلاحِ معاشرہ کے حوالے سے چھ تقاضے اہم ہیں:
(۱) صحیح نیت
(۲) اخلاص
(۳) تقویٰ
(۴) علم
(۵) خدمت
(۶) استقامت
تجزیہ کیا جائے تو مسلمان کی پوری زندگی صحیح نیت پر کھڑی ہوئی ہے۔ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا ہے کہ ’’عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔‘‘ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسی نیت ہوگی ویسا ہی عمل ہوگا۔ نیت صحیح ہوگی تو عمل بھی صحیح ہوگا۔ نیت خراب ہوگی تو عمل بھی خراب ہوگا۔ نیت میں وضاحت ہوگی تو عمل میں بھی وضاحت ہوگی، نیت میں ابہام ہوگا تو عمل میں بھی ابہام ہوگا۔ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ کام کرنے والا اپنے ہر عمل کو اللہ کے لیے خالص کرلے۔ اسے اپنے عمل سے نہ شہرت درکار ہو، نہ دولت درکار ہو، نہ عہدہ درکار ہو۔ نیت کی درستی اور اخلاص سے اللہ تعالیٰ تھوڑے کام کو بہت کردیتا ہے۔
تقویٰ کی اہمیت یہ ہے کہ تقویٰ انسانی قلوب کو متاثر کرتا ہے اور اصلاحِ معاشرہ کے حوالے سے اصل چیز یہی ہے کہ اصلاح کرنے والا لوگوں کے قلوب پر اثر انداز ہوسکے۔ اصلاحِ معاشرہ کے سلسلے میں علم کی اہمیت یہ ہے کہ صحیح عمل صحیح علم کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ علم کی دوسری اہمیت یہ ہے کہ علم لوگوں کے اذہان پر اثر انداز ہوتا ہے۔ خدمت کا معاملہ یہ ہے کہ وہ محبت پیدا کرتی ہے اور محبت افراد کے درمیان اجنبیت کی تمام دیواروں کو منہدم کرکے انسان کی قلبِ ماہیت کی راہ ہموار کردیتی ہے۔ استقامت اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ اس لیے کہ استقامت ظاہر کرتی ہے کہ انسان نے کوئی کام کسی وقتی جوش کے تحت نہیں کیا بلکہ اس کا شعور اس کام کا محرک ہے۔ استقامت کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ انسان نے اپنے کام کا نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا ہے اور وہ اللہ ہی پر بھروسہ کرتا ہے۔
کسی انسان یا گروہ نے اصلاحِ معاشرہ کے لیے جب بھی ان تقاضوں کو پورا کیا ہے، ہمیشہ اس کے مثبت نتائج برآمد ہوئے ہیں۔
——